امید پہ دنیا قائم ہے (3)
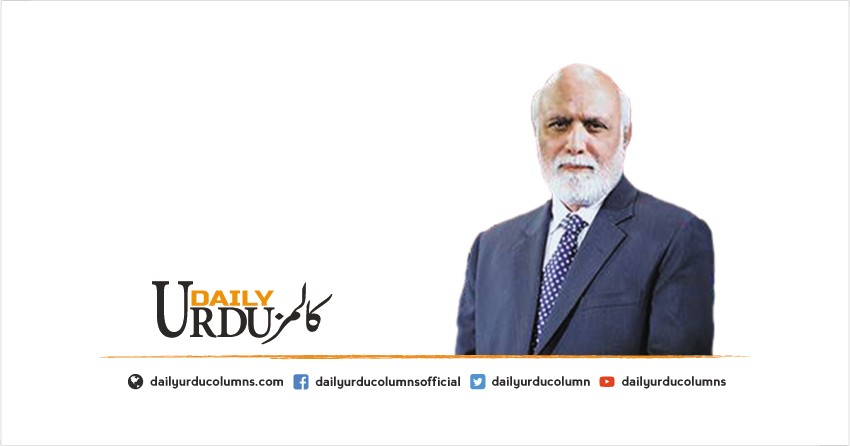
عروج کی طرح زوال بھی ہمہ گیر ہوتا ہے۔ سیاست میں کبھی قائد اعظم تھے۔ اب زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف اور عمران خان۔ ظفر علی خان اور محمد علی جوہر صحافت کی آبرو تھے۔ اب مجھ ایسے کج مج بیاں۔ اللہ جانے زوال کا یہ سفر کب تھمے گا۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ محترمہ مریم نواز سے تو عرض نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے والدِ گرامی سے التماس ہے کہ آگ اتنی نہ بھڑکائیں کہ سب کچھ ہی جل بجھے۔
انچاس برس ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کا ایک جلوس میکلوڈ روڈ سے گزرا۔ روزنامہ کوہستان مرحوم میں یہ ناچیز ادارتی صفحے کا انچارج تھا۔ انچارج کیا، صحافت کے بہترین اساتذہ میں سے ایک سید عالی رضوی کا مددگار۔ انہیں ایک نائب کی ضرورت پڑی تو نیوز روم سے میرا تبادلہ ادارتی سیکشن میں کر دیا گیا۔ عمر میری مبلغ اکیس برس تھی۔ کبھی کبھار وہ خلیل ملک مرحوم یا خاکسار کو ادارتی نوٹ یا اپنے کالم "آج کی باتیں " کا ایک حصہ لکھنے کا حکم دیتے۔ خلیل ملک میں اعتماد بہت تھا۔ میں التجا کرتا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ وہ اہلِ زبان تھے مگر بات پنجابی میں کرتے۔ ایل ایل بی کے طالبِ علم تھے کہ عنایت اللہ مرحوم کی نظر ان پر پڑی اور وہ اداریہ نویس ہو گئے۔ مجبوراً ادارتی نوٹ لکھا جاتا اور تین چار حصوں پر مشتمل کالم کا ایک ٹکڑا بھی۔ رفتہ رفتہ کچھ اعتماد پیدا ہوا تو گاہے بہ گاہے کالم لکھنے لگا۔
انہی دنوں تاریخ ساز ناول نویس نسیم حجازی نے کہ چیف ایڈیٹر تھے، طلب کیا اور حکم دیا کہ یہ ایک انٹرویو ہے، اسے مضمون بنا دو۔ میں حیران کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ 21 سال کی عمر کا ایک اخبار نویس جو صرف دو سال کا تجربہ رکھتا تھا، اس پل صراط کو کیسے پار کرے۔ بولے: مجھے نہیں معلوم، جاؤ اور اپنا کام کرو۔ آدھی رات تک میں جتا رہا؛ حتیٰ کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تمام نکات نوٹ کیے۔ اہم اور غیر اہم نکات میں کچھ نہ کچھ امتیاز کرنے لگا تھا اور یہ کہ عبارت میں ربط کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے۔ نسیم حجازی صاحب کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ داد تو کیا ملتی، یہی غنیمت تھا کہ کوئی اعتراض نہ کیا۔
کچھ دن گزرے ہوں گے کہ حجازی صاحب نے پھر طلب کیا۔ حکم دیا: کرشن نگر کے مسائل پر ایک فیچر لکھو۔ میری بلا جانے کہ فیچر کیا ہوتا ہے۔ میکلوڈ روڈ پر ہراساں اور حیران میں چلا جاتا تھا کہ ایک سینئر اخبار نویس سے ملاقات ہو ئی۔ مسئلہ بیان کیا تو وہ ہنسے اور یہ کہا: تم نسیم صاحب سے بہتر فیچر لکھ سکتے ہو۔ میں اورگھبرایا۔ نسیم صاحب سے بہتر؟ اس وقت میری نگاہ میں وہ پاکستان کے سب سے بڑے قلمکار تھے۔ اب یاد نہیں پڑتا کہ وہ فیچر لکھا جا سکا یا نہیں۔
میکلوڈ روڈ پر پیپلز پارٹی کے جلوس سے ایک خیال اخذ کیا اور کالم لکھا۔ عالی رضوی صاحب نے پڑھا اور بولے: یہ جملہ تم نے کیسے لکھ دیا؟ حیرت سے عرض کیا: یہ ایک نعرے کا ذکر ہے، جو اس جلوس میں لگایا گیا۔ ناراضی سے دیکھا اور یہ کہا: تحریر اور گفتگو کی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ بے فکروں کا ایک ہجوم کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر وہ گالی بکیں تو کیا تم نقل کر دو گے؟ ان کے ارشاد پر غور کیا تو ایک نکتہ ادراک میں آیا: تحریر کی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ کسی تکدّر کے بغیر کمسن بچی سے لے کر ایک بزرگ تک سبھی پڑھ سکیں۔
شائستگی کے علاوہ ایک چیز فصاحت بھی ہوتی ہے۔ موزوں ترین لفظ کا استعمال۔ شاعری اور فکشن کا مطالعہ بھی جاری رہا۔ معلوم ہوا کہ لکھنے والے کے معیار کا تعین تشبیہ پر ہوتا ہے، استعارے اور مثال پر۔ کہاں سے کسی نے تشبیہ اٹھائی؟ تاریخ سے؟ ادب سے؟ دینیات سے؟ مناظرِ قدرت سے؟
دس سال ہوتے ہیں، میں ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ موسیقی کی شد بد رکھنے والے طاہر سرور میر نے پوچھا: اردو کس سے پڑھی؟ عرض کیا: کبھی تفصیل بھی عرض کروں گا، مختصراً یہ کہ بڑے غلام علی خاں سے۔ انیس احمد اعظمی تعمیرِ ملّت ہائی سکول رحیم یار خاں میں ہمارے استاد تھے۔ جناب سرور صدیقی اور چوہدری عبدالمالک بھی۔ ڈاکٹر صفدر محمود انہی کے شاگرد ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب ایسے ریاضت کیش نہ تھے۔ امریکہ میں مقیم دنیا کے بہترین برین سرجن ڈاکٹر سعید باجوہ بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ سکول میں مجھ سے ایک سال پیچھے ہوا کرتے۔
جون 1992ء سے مارچ 1993ء تک، ناچیز اسلام آباد کے ایک اخبار کا نیوز ایڈیٹر رہا۔ اساتذہ کے طفیل جو کچھ ازبر تھا، اس کی بنا پر صحتِ زبان پہ اصرار کرتا رہا تو بعض جواں سال اخبار نویس کسمساتے۔ ان میں سے ایک نے بگڑ کر کہا: آپ نے تو ہمیں سکول کے بچّے بنا دیا۔ اس کے بعد احتیاط برتنے لگا کہ نوجوانوں کا مزاج مختلف ہے۔ پھر بھی ان میں سے بعض صحافت کے آسمان پر ستاروں کی طرح دمک رہے ہیں۔ میرا کچھ کمال نہ تھا۔ کبھی یاد دہانی کرا دیتا۔ طالبِ علم اپنے اشتیاق سے سیکھتا ہے۔ انہی میں سے ایک اسلم خان نے مجھے استاد کہنا شروع کیا جو رفتہ رفتہ رائج ہوتا گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس پہ شرمندہ ہی رہا۔ چھپنے کے بعد اپنا کالم پڑھتا ہوں تو ایک آدھ نہیں، کئی غلطیاں کھٹکتی ہیں۔ اساتذہ کے طفیل... اور ان میں ظہیر کاشمیری مرحوم کے علاوہ ڈاکٹر خورشید رضوی اور افتخار عارف شامل ہیں، بعض الفاظ مثلاً "نہ" اور "نہیں " میں امتیاز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔"انٹر ویو کے دوران" کی بجائے "انٹرویو میں " لکھتا ہوں۔"اس ملک کی عوام" نہیں "ملک کے عوام"۔
صحافت اب آزاد ہے۔ اخبار نویس بادشاہت پر تلے ہیں۔ جنگل کے بادشاہ، انڈے دیں یا بچّے۔ سیاستدانوں کا حال بھی یہی ہے۔ کتاب سے واسطہ ہے اور نہ اہلِ قلم سے۔ سید مشاہد حسین بڑے ہی ذہین آدمی ہیں مگر انگلش میڈیم۔ لاہور کی بازاری زبان کے بعض لفظ ان کی وجہ سے رائج ہو گئے۔ مشاہد حسین تو خیر صاحبِ ذوق ہیں۔ چند ایک غلطیاں ہی ان سے سرزد ہوئیں۔ نئے لیڈروں اور صحافیوں کے استاد اب شیخ رشید ہیں۔
لفظوں کے خاندان ہوتے ہیں، نسلیں اور رشتے ناطے بھی۔ چودہ سو سال پہلے رحمتہ اللعالمینؐ جن لوگوں میں مبعوث کیے گئے، جہالت کے باوجود، وہ بعض اوصاف کے حامل تھے۔ وعدے کے پکے، مہمان نواز اور سخت جان۔ فصاحت کے اعتبار سے تاریخِ انسانی کے بہترین لوگ۔ وہی قرآنِ کریم کے اعجاز کو پا سکتے تھے۔ وہی ختم المرسلینؐ کی فصاحت سے اکتسابِ نور کے اہل تھے۔ لاکھوں احادیث ہیں مگر خود ستائی ایک میں بھی نہیں۔ یہ البتہ ارشاد کیا: مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ فرمایا: فصاحت مرد کا زیور ہے۔
سیکھنے کو لازم ہے کہ آدمی آرزومند ہو۔ حمید اختر مرحوم کو یہ طالبِ علم ہمیشہ غور سے پڑھا کرتا۔ مسعود اشعر اور انتظار حسین کوبھی۔ منّو بھائی اور عبدالقادر حسن نے بھی ایک زمانے میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔
عروج کی طرح زوال بھی ہمہ گیر ہوتا ہے۔ سیاست میں کبھی قائد اعظم تھے۔ اب زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف اور عمران خان۔ ظفر علی خان اور محمد علی جوہر صحافت کی آبرو تھے۔ اب مجھ ایسے کج مج بیاں۔ اللہ جانے زوال کا یہ سفر کب تھمے گا۔ امید پہ دنیا قائم ہے

